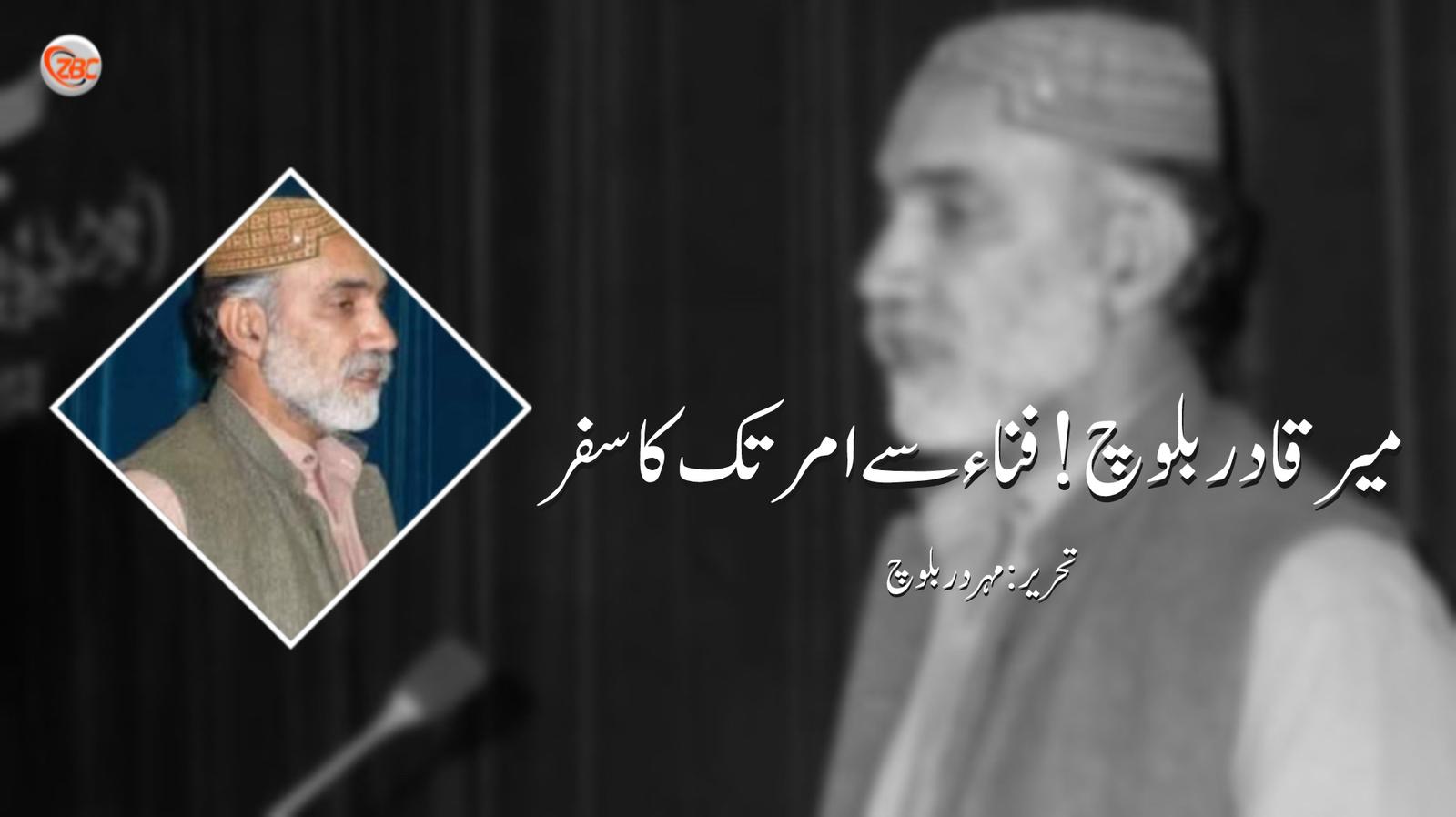
تحریر: مہر در بلوچ
زرمبش مضمون
بلوچ قوم کی تاریخ جدوجہد، قربانیوں اور قربان گاہوں کی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ یہ تاریخ اُن بے شمار کرداروں کے خون سے لکھی گئی ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قومی وقار،آزادی ، شناخت اور سرزمین کے تحفظ کے لیے وقف کیا۔ انہی عظیم کرداروں میں ایک نام میر قادر بلوچ کا ہے، جو نہ صرف ایک سیاسی باسک اور نظریاتی رہنما تھے بلکہ بلوچ قومی تحریک آزادی کے ایک ناقابلِ فراموش باب بھی ہیں۔ آج اُن کی تیسری برسی ہے، مگر اُن کی یاد، فکر اور عزم اب بھی بلوچ تحریک کے لیے ایک صبحِ صادق کی مانند ہے۔میر قادر بلوچ سے میرا سیاسی تعلق اُس وقت قائم ہوا جب میں 2004 میں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن (بی ایس او) کا سیکریٹری جنرل تھا اور وہ بلوچ نیشنل موومنٹ (BNM) کی مرکزی کمیٹی کے رکن تھے۔ یہ تعلق محض رسمی یا وقتی نہیں تھا بلکہ دو دہائیوں تک ایک مضبوط نظریاتی رشتے کی صورت میں قائم رہا۔ ان سالوں میں، میں نے میر قادر بلوچ کو نہ صرف ایک باہمت اور نڈر سیاسی ساتھی کے طور پر پایا بلکہ ایک ایسے باشعور رہنما کے طور پر بھی، جو قومی مقصد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔
میر قادر بلوچ کی زندگی ایک فرد نہیں ، بلکہ ایک عہد، اور ایک نظریہ تھے جس نے غلامی کی سیاہ راتوں میں روشنی کے چراغ جلائے۔ میں نے میر صاحب کو بیس برس کے طویل عرصے تک قریب سے جانا، ان کے ساتھ سفر کیا، جدوجہد کی راہوں پر سنگتی کی، مباحثوں اور مکالموں میں شریک ہوا، اور ان کے فکر و شعور کے ارتقاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ رشتہ محض سیاسی نہیں بلکہ فکری، نظریاتی اور روحانی بھی تھا۔ آج جب میں ان کی یادوں، باتوں، ہنسی، دکھ، آدرش اور قربانیوں کو یاد کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی قیمتی میراث ہے جسے لفظوں میں سمونا آسان نہیں۔اس کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی سادگی اور خاکساری تھی۔ وہ ایسے رہنما تھے جو اقتدار، دولت یا ذاتی مفاد کے پیچھے نہیں دوڑتے تھے بلکہ اپنی ہر سانس اور لمحہ قومی تحریک کے نام وقف کرتے تھے۔ ان کا کردار بے داغ، موقف واضح اور نظریہ خالص تھا۔ وہ ذاتی تذبذب سے پاک تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان پر اعتماد کیا جاسکتا تھا۔ ان کے نزدیک سیاست ذاتی فائدے کا نہیں بلکہ قومی آزادی اور وقار کا نام تھی۔ ان کی گفتگو ہمیشہ فکری بنیادوں پر استوار ہوتی، وہ مسائل کو سطحی نہیں دیکھتے تھے بلکہ ان کے اسباب، تاریخی پس منظر اور سیاسی تناظر کو کھول کر بیان کرتے تھے۔
مسقط میں آرام دہ اور پرتعیش زندگی چھوڑ کر واپس آنا کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ قدم اس بات کا اعلان تھا کہ میر قادر بلوچ کے لیے ذاتی سکون، آسائش اور مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان کے سینے میں ایک ایسی قوم پرور تڑپ تھی جو انہیں دیارِ غیر میں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ جب بلوچستان میں ایک نئی مزاحمتی لہر اٹھی، جب قوم غلامی کے شکنجوں سے نجات کے لیے ایک بار پھر متحد ہونے لگی، تو میر قادر بلوچ کے دل کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ وہ اس تحریک کے کنارے تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ وطن کی مٹی کا جادو تھا، شہیدوں کے خون کی پکار تھی، اور قوم کی غلامی کا درد تھا جو انہیں واپس لے آیا۔واپس آنے کے بعد اس نے عملی جدوجہد کے ذریعے مزاحمت کو سیاسی، فکری اور جمہوری پراسس کا حصہ ثابت کیا۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ غلام قوم کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی حالتِ غلامی کو فطری سمجھنے لگتی ہے، اور مزاحمت اس وقت جنم لیتی ہے جب قوم اس غلامی کو اپنی توہین سمجھے۔ ان کے نزدیک آزادی کے بغیر کوئی ثقافت زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی زبان پروان نہیں چڑھ سکتی، اور کوئی قوم عزت سے نہیں جی سکتی۔
میر قادر بلوچ کی زندگی میں قربانی ایک مستقل عنصر تھی۔ انہوں نے ذاتی مفادات کو کبھی قومی مقصد پر غالب نہیں آنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مزاحمتی تحریک کے ایک ایسے معمار بنے جنہوں نے نہ صرف سیاسی محاذ کو مضبوط کیا بلکہ فکری بنیادوں کو بھی گہرائی بخشی۔ ان کی سنگتی میں خلوص اور محبت تھی۔ وہ ساتھیوں کے ساتھ کسی رہنما کے طور پر نہیں بلکہ ایک ہمسفر کے طور پر رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے تھے اور ان پر بھروسہ کرتے تھے۔آج جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو یہ محض ایک فرد کی یاد نہیں بلکہ ایک عہد کی یاد ہے۔ ان کا نام اس مزاحمتی تاریخ کا حصہ ہے جو بلوچستان کی مٹی میں شہیدوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ وہ اس تحریک کے ان کرداروں میں شامل ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ غلامی کے خلاف جنگ ایک مسلسل فکری، سیاسی اور عملی جدوجہد ہے۔ ان کی تقریریں جلسوں کے ہجوم میں شور پیدا نہیں کرتیں بلکہ دلوں میں انقلاب کی آگ بھڑکاتی تھیں۔ ان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ گولیوں کی طرح دشمن کے قلعوں کو ہلا دیتے اور بلوچ قوم کے سینہ میں امید کا دیا روشن کر دیتے۔
ان کی منفرد متحرک پہچان ان کی بے باکی تھی۔ جب وہ تقریر کے لیے اسٹیج پر آتے تو ان کا وجود خود ایک اعلانِ مزاحمت ہوتا۔ وہ مصلحتوں اور ڈپلومیسی کی گہری چادروں کو چاک کر کے بات کرتے۔ ان کے الفاظ میں کوئی گھما پھرا نہیں ہوتا، کوئی سیاسی اصطلاحات کا بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ سادگی اور سچائی کا خالص رنگ ہوتا۔ وہ سیدھا دل سے بولتے اور سیدھا دلوں تک پہنچتے۔بہت سے ساتھی اکثر ان سے کہتے کہ:
"آپ بہت زیادہ جذباتی تقریریں کرتے ہیں، ذرا محتاط ہوا کریں۔”لیکن اس کا جواب ہمیشہ ان کے اندازِ خطابت کی طرح واضح اور دوٹوک ہوتا۔ وہ کہتے:
"جب میری قوم کا لہو بہہ رہا ہے، جب میری سرزمین نوآبادیاتی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، تو میں کیسے ٹھنڈی اور حساب شدہ زبان بول سکتا ہوں؟”
یہی وہ جوش خطابت تھا جو ان کے لہجے میں گرج اور جرأت پیدا کرتا تھا۔ جب وہ بولتے تو ان کی آواز استعمار کے ایوانوں کو لرزا دیتی، اور غلامی کے زخموں سے نڈھال عوام کے دلوں میں حوصلہ اور ولولہ بھر دیتی۔ وہ الفاظ کے نہیں، سچائی کے جنگجو تھے، جو کالونیلسٹ کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتے، اور ظلم و جبر کے ہر بت کو للکارتے۔
۔ ان کے ہر جملے میں تاریخ کی بازگشت، حال کا کرب، اور مستقبل کی نوید شامل ہوتی۔ اسی لیے وہ تقریر کو صرف سیاسی ہتھیار نہیں بلکہ آگاہی اور شعور کی مشعل سمجھتے تھے۔
ان کے بے باک موقف کی قیمت انہیں بارہا ادا کرنی پڑی۔ دورانِ جدوجہد وہ متعدد بار جیلوں میں ڈالے گئے، سالوں تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ مگر قید کی تاریک کوٹھڑیاں بھی ان کی آواز کو خاموش نہ کر سکیں۔ وہ جیل کی دیواروں سے بھی صدائے احتجاج بلند کرتے رہے۔
ان پر بے شمار سیاسی مقدمات قائم کیے گئے، جن میں اشتعال انگیزی، بلوچ قوم کو مزاحمت پر اکسانے، اور بلوچ قومی آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے الزامات سرِفہرست تھے۔ لیکن وہ ہر مقدمے، ہر الزام، اور ہر دھمکی کے باوجود اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔
یہی ان کی اصل عظمت تھی کہ انہوں نے مزاحمت کو اپنی زندگی کا محور بنایا اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہے۔ ان کا یقین تھا کہ غلامی کے خلاف جدوجہد میں سمجھوتہ سب سے بڑی غداری ہے۔ اس لیے وہ اپنے الفاظ اور عمل دونوں میں ثابت قدم رہے۔ ان کے الفاظ میں تاریخ کے شہیدوں کا لہو بولتا تھا، بلوچ ماؤں کے آنسوؤں کی سچائی بولتی تھی، اور ان نوجوانوں کی امید بولتی تھی جو غلامی کے اندھیروں سے آزادی کی روشنی کی تلاش میں نکلے تھے۔
جب وہ جلسوں میں خطاب کرتے تو ہجوم محض سامعین نہیں رہتا بلکہ ایک تحریک میں ڈھل جاتا۔ ان کی تقریر سننے والے لوگ محض سن کر واپس نہیں جاتے تھے، وہ اس تقریر کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیتے تھے۔ یہی ان کا کمال تھا کہ وہ لفظوں کو عمل میں بدلنے کی طاقت رکھتے تھے۔ان کی شخصیت ایک طرف انقلابی رہنما کی جرأت سے مزین تھی، تو دوسری طرف عاجزی اور خاکساری سے بھی لبریز تھی۔ وہ کبھی بھی خود کو لیڈر کے طور پر پیش نہیں کرتے تھے بلکہ ایک سنگت اور ہمسفر کے طور پر قوم کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔
ان کی بلوچ دوست سیاست میں شمولیت محض ایک اتفاق نہیں تھی، بلکہ اُن کا بچپن اور تربیت ایسے نظریاتی ماحول میں گزری جہاں قومی خودمختاری کے خواب پروان چڑھتے تھے۔ اُن کے اندر موجود یہ شعور اور عزم انہیں قدرتی طور پر اُس راستے پر لے آیا جس پر چلنے والے اکثر لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ میر قادر بلوچ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو بلوچ قومی تحریک کے آغاز سے ہی اس جدوجہد کا حصہ رہا۔اُن کے والد نے 1958 کی بلوچ مزاحمتی تحریک میں بابو نوروز خان کے شانہ بشانہ جدوجہد کی، جو اُس وقت کی بلوچ مزاحمتی تاریخ کا سنگِ میل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب بلوچستان میں پہلی بار منظم طور پر ریاستی جبر کے خلاف علمِ مزاحمت بلند ہوا۔ میر قادر بلوچ کے والد کی یہ قربانی اُن کے لیے محض ایک تاریخی حوالہ نہیں تھی، بلکہ ایک انقلابی ورثہ تھا جو اُن کی رگ و پے میں شامل تھا۔
اسی طرح میر قادر کے بھائی، شہید سفر خان بلوچ، بھی قومی تحریک آزادی کے ایک اہم اور سرگرم کردار تھے۔ سفر خان کی شہادت نے میر قادر کے نظریے کو مزید مضبوط کیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ یہ جدوجہد جز وقتی نہیں بلکہ نسل در نسل قربانیوں کا تقاضا کرتی ہے۔وہ محض ایک سیاسی رہنما نہیں، بلکہ ایک نظریاتی شخصیت تھے۔ اُن کے نزدیک سیاست اقتدار کی دوڑ نہیں بلکہ ایک مقدس عہد تھا، جو اپنی سرزمین، اپنی زبان، اور اپنے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میر قادر کی شخصیت میں یہ خاصیت تھی کہ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جدوجہد کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر تحریک کا نظریہ واضح اور مضبوط ہو تو کوئی طاقت اُسے کچل نہیں سکتی۔اس کی جدوجہد کا سب سے نمایاں پہلو اُن کی جرأت اور بے خوفی تھی۔ وہ ہمیشہ سچ بولتے اور جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہتے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔
آج جب ہم ان کی تیسری برسی منا رہے ہیں، تو یہ محض اُنہیں یاد کرنے کا دن نہیں بلکہ بلوچ تاریخ، قربانیوں اور مستقبل کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تحریکیں نظریے، قربانی اور عملی جدوجہد کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہیں۔ اس نے اپنے وجود کو ذاتی مفاد، قبیلائی سیاست یا وقتی شہرت کی قربان گاہ پر نہیں چڑھایا بلکہ اپنی تمام توانائیاں ایک ایسے خواب کی تعبیر کے لیے وقف کیں جو ذاتی نہیں، بلکہ اجتماعی تھا۔
انسانی تاریخ کے صفحات ہمیشہ اُن افراد کے تذکروں سے روشن رہے ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو پسِ پشت ڈال کر قومی مقاصد کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیں۔ ایسے لوگ محض زندہ انسان نہیں رہتے بلکہ وہ ایک نظریہ بن جاتے ہیں، اور نظریات کو مٹانا کسی طاقت کے بس کی بات نہیں۔ نوآبادیاتی نظام کے خلاف مزاحمت کرنے والے یہ افراد تاریخ کے وہ درخشندہ ستارے ہیں جو غلام قوموں کے لیے رہنمائی کے مینار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غلامی صرف جسمانی قید کا نام نہیں بلکہ یہ ذہنوں کو مفلوج کرنے کا عمل ہے۔ ایک غلام قوم اُس وقت تک اپنی اہداف حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اس ذہنی غلامی سے نجات نہ پائے۔ اس حقیقت کو سب سے پہلے سمجھنے اور اجاگر کرنے والے ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کو قربان کر کے اجتماعی شعور کو بیدار کرتے ہیں۔ اس نے بلوچ قوم کو یہ باور کرایا کہ قومی خود مختیاری محض ایک سیاسی نعرہ نہیں بلکہ یہ انسان کی فطری ضرورت اور بنیادی حق ہے۔ نظریاتی سطح پر مزاحمت کو عملی شکل دینا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مگر اس نے عملی جدوجہد میں بھی اپنی قیادت کا لوہا منوایا۔ اُس کی زندگی قید و بند، جلاوطنی اور قربانیوں سے عبارت رہی، مگر وہ کبھی پیچھے نہ ہٹےتاریخ کے صفحات میں ایسے کردار کبھی مٹائے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ جسمانی طور پر تو فانی ہوتے ہیں مگر ان کے نظریات اور افکار زندہ رہتے ہیں۔
تاریخ ہمیشہ اُن لوگوں کے نام کو اپنے سنہری اور تابندہ حروف میں محفوظ رکھتی ہے جنہوں نے اپنے لہو اور جدوجہد سے حریت کے چراغ جلائے اور غلامی کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کی کوشش کی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے وجود کو وقت کی گرد مٹا نہیں سکتی، کیونکہ وہ محض انسان نہیں رہتے، وہ ایک نظریہ، ایک روشنی، ایک تحریک اور ایک صدا بن جاتے ہیں۔ میر قادر کی جدوجہد اور قربانی کو صرف ایک رسمی تقریب یا الفاظ کے چند جملوں کے ذریعے خراجِ عقیدت پیش کر دینا، کافی نہیں ایسا کرنا محض ایک رسم ادا کرنے کے مترادف ہوگا، اس نے اپنی جدوجہد سے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی محض سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے جانے کے بعد بھی اُس کی جدوجہد، اُس کی سوچ اور اُس کا کردار زندہ رہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ "زندگی تو ہر حال میں گزر جائے گی، مگر اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد بھی آپ کی زندگی کی گواہی دے۔”یہ ایک ایسا انقلابی تصور ہے جو غلامی کے شکنجے میں جکڑی ہوئی قوموں کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ اس نے نہ صرف اس فلسفے کو بیان کیا بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کو مجسم کر کے دکھایا۔ انہوں نے اپنی ذات کو فنا کے اندھیروں میں گم نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے نظریات، حوصلے اور قربانیوں کے ذریعے خود کو امر کر دیا۔اس نے باور کرایا کہ غلامی کو تقدیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ غلامی کو چیلنج کرنا ہی جدوجہد کی پہلی سیڑھی ہے۔ ان کی تیسری برسی تعزیت کا لمحہ نہیں ، بلکہ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں۔ وہ اپنے جسمانی وجود کے ساتھ نہیں مگر اپنی فکر، اپنے نظریات اور اپنی جدوجہد کے ساتھ زندہ ہیں۔
اگر ہم میر قادر بلوچ کو صرف الفاظ کے ہار پہنائیں اور عملی جدوجہد سے دستبردار رہیں، تو یہ ان کی قربانیوں کی توہین ہوگی۔ ان کو حقیقی خراجِ عقیدت پیش کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم ان کے نظریات کو اپنی جدوجہد کا حصہ بنائیں، اور ان کی قربانی کو اپنی راہ کا چراغ بنائیں۔ اگر ہم ان کے نظریات کو عملی میدان میں زندہ نہ رکھ سکے تو ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ان کی زندگی اور جدوجہد ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ عظیم مقصد کا خواب کبھی فنا نہیں ہو سکتا، اور وہ لوگ جو اس خواب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، وقت کے دائرے سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے نظریے کو ایک زندہ حقیقت میں بدلیں، کیونکہ یہی وہ حقیقی خراجِ عقیدت ہوگا جو ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ ان کے خیالات، ان کے حوصلے اور ان کی قربانیاں ہمیشہ جدوجہد کی طاقت اور قوت بنتی رہیں گی،
غلامی محض ایک سیاسی یا معاشی حقیقت نہیں بلکہ ایک ایسی مہلک افیون ہے جو قوموں کے شعور کو مفلوج کر دیتی ہے۔ یہ ایک سرطان ہے جو خاموشی سے جسم کو نہیں بلکہ روح کو چاٹتا ہے، ذہنوں کو مفلوج کرتا ہے، اور اجتماعی حوصلوں کو گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے۔ غلامی سب سے پہلے انسان کی شناخت کو مسخ کرتی ہے، اس کی تہذیب و تمدن کو مٹا دیتی ہے، اس کے کلچر اور زبان کو اجنبی بنا دیتی ہے، اور آخر کار اس کی قومی بقا کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔جب قومیں غلامی کے اس زہر کو تقدیر سمجھ کر پینے لگتی ہیں تو وہ ظاہری طور پر زندہ رہتی ہیں مگر اندر سے مردہ ہو جاتی ہیں۔ قربانی، اذیت اور جدوجہد سے آنکھیں موند لینا بظاہر زندگی کو آسان بنا سکتا ہے، مگر یہ آسودگی اور مراعاتی زندگی درحقیقت اجتماعی موت کا اعلان ہے۔ اس وقت کے بعد زندگی محض سانسوں کا تسلسل رہ جاتی ہے، اور تاریخ ایسی قوموں کو کبھی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کرتی۔ وہ تاریخ کے کچرے دان میں پھینک دی جاتی ہیں، ان کے وجود پر شرمندگی کی مہر ثبت کر دی جاتی ہے۔
غلامی کا سب سے پہلا وار قومی شعور پر ہوتا ہے۔ جب ایک قوم کا شعور کمزور پڑ جاتا ہے تو وہ اپنی حالتِ غلامی کو تسلیم کر لیتی ہے۔ ایسے میں بظاہر امن قائم رہتا ہے، مگر یہ امن موت کا سکوت ہوتا ہے، ایک ایسا سکوت جو ہر دھڑکن کو خاموش کر دیتا ہے۔ایسے وقت میں تاریخ چند ایسے افراد کو جنم دیتی ہے جو قوم کے اندر بجھتے ہوئے چراغوں کو دوبارہ روشن کرتے ہیں۔ یہ وہ بہادر اور مخلص فرزند ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے بلند ہو کر پوری قوم کے لیے جدوجہد کا علم اٹھاتے ہیں۔ ان کے حوصلے، قربانیاں اور اذیتیں صرف ان کی ذاتی کہانی نہیں رہتیں بلکہ وہ پوری قوم کے لیے مشعلِ راہ بن جاتی ہیں۔تاریخ ہمیشہ ان بہادروں پر فخر کرتی ہے۔ ایسے فرزندوں کو یاد کرنا دراصل اپنی ذمہ داریوں کا اعتراف ہے، اور اس اعتراف کو عملی جدوجہد میں ڈھالے بغیر ہم ان کے مقصد کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔
میر قادر نے اس فلسفے کو اپنی عملی زندگی سے سچ ثابت کیا۔ ان کی قربانیاں اور جدوجہد آج بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ جسمانی طور پر ہمارے درمیان نہ رہنے کے باوجود اپنی فکر اور حوصلے کے ذریعے زندہ ہیں۔ ۔آج جب ہم ان کی برسی کے دن انہیں یاد کرتے ہی تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ وہ فنا نہیں ہوئے۔ وہ اپنی سوچ، اپنے نظریے، اور اپنی جدوجہد کے ذریعے امر ہو گئے ہیں۔ ان کے خیالات اور ان کے حوصلے آنے والی نسلوں کے لیے آزادی کی جدوجہد کی سب سے بڑی طاقت اور قوت ہوں گے۔
یہ وقت ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی مٹی، اپنی زبان، اپنی ثقافت، اور اپنی آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی، تو آنے والی نسلیں ہمیں غلامی کے داغدار ورثے کے ساتھ یاد کریں گی، اور تاریخ ہمارے بارے میں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں لکھے گی۔
تاریخ کے دامن میں وہی نام ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتے ہیں جو اپنے وجود کو ذاتی مفادات، وقتی آسائشوں اور فانی جسمانی زندگی سے بلند کر کے ایک نظریہ میں ڈھال لیتے ہیں۔ افراد مٹ جاتے ہیں، سلطنتیں ٹوٹ جاتی ہیں، طاقتور زوال پذیر ہو جاتے ہیں، لیکن نظریات وقت کے ہر طوفان کو شکست دیتے ہوئے نسل در نسل اپنی روشنی کو منتقل کرتے رہتے ہیں۔ میر قادر انہی ہستیوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو محض ایک انسان کی حد تک محدود نہ رہنے دیا بلکہ اپنے کردار، قربانی اور جدوجہد کے ذریعے ایک ایسے نظریے کا روپ دھارا جو غلامی کے اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ فنا نہیں ہوئے، کیونکہ نظریات مر نہیں سکتے۔ وہ امر ہو گئے ہیں۔فنا محض جسمانی موت کا نام نہیں، بلکہ یہ اس وقت آتی ہے جب ایک فرد یا قوم اپنے شعور، اپنی شناخت اور اپنے مقصد کو کھو بیٹھتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنی زندگی کو صرف ذاتی آسائشوں اور وقتی خواہشات کے گرد محدود کر دیتا ہے، تو وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس، امر ہونا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کوئی فرد اپنے وجود کو ایک ایسے نظریے میں ڈھال دیتا ہے جو وقت، مقام اور جسمانی فنا سے ماورا ہو۔وہ جانتے تھے کہ غلامی کے خلاف لڑنے والا ہر شخص طاقتور دشمنوں کے نشانے پر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے موت کو ایک اختتام نہیں بلکہ آغاز سمجھا۔ ان کے لیے جسمانی فنا محض ایک مرحلہ تھا، کیونکہ وہ اپنی فکر اور جدوجہد کو اس مقام تک لے گئے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔
تاریخ کا یہ مستند سبق ہے کہ نظریات کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ سلطنتیں نظریات کو دبانے کے لیے قید و بند، اذیت اور حتیٰ کہ قتل و غارت کا سہارا لیتی ہیں، لیکن جب کوئی نظریہ عوام کے دلوں اور ذہنوں میں جگہ بنا لیتا ہے تو وہ ایک ایسی آگ بن جاتا ہے جو ہر رکاوٹ کو جلا دیتی ہے۔
میر قادر بلوچ کا نظریہ آزادی، خودمختاری، اور انسانی وقار کا نظریہ ہے۔ یہ نظریہ اس یقین پر مبنی ہے کہ غلامی صرف جسموں کو قید نہیں کرتی بلکہ روحوں کو زنجیروں میں جکڑتی ہے۔ اس زنجیر کو توڑنے کے لیے قربانی ناگزیر ہے۔
اس کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی قومی جدوجہد سے والہانہ وابستگی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بلوچ قومی آزادی کے نام وقف کیا اور کبھی بھی اپنے موقف، نظریات یا سیاسی عمل میں کمزوری نہیں دکھائی۔ وہ سمجھتے تھے کہ قومی خوداختیاری کی راہ میں کوئی سمجھوتہ دراصل ضمیر کی موت کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر قسم کے سیاسی دباؤ، جبر، اور لالچ کے باوجود اپنی راہ سے ایک انچ نہ ہٹے۔وہ اکثر کہا کرتے تھے:
"وطن کی آزادی پر سمجھوتہ میرے لیے اپنی روح کو بیچنے کے برابر ہے، اور میں اپنی روح کو غلامی کی منڈی میں کبھی نہیں بیچوں گا۔”
اس کے لیے سیاست کوئی پیشہ نہیں بلکہ ایک مقدس عہد تھا۔ وہ بلوچ ازم اور فکرِ خیر بخش کے بڑے پاسدار تھے۔ ان کے نزدیک بلوچ نیشنلزم محض ایک نظریہ نہیں بلکہ ایک طرزِ حیات تھا۔ ان کی زندگی بلوچ عوام کے سامنے ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ وہ بطور انسان غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا قد و قامت، سادگی، عاجزی، اور خلوص انہیں دوسروں سے منفرد بناتا تھا۔ وہ سنگتوں درمیان ایک رہنما سے زیادہ ایک دوست، ایک بھائی، اور ایک ہمدرد بن کر رہتے تھے۔ ان کی موجودگی حوصلے اور امید کی علامت تھی۔ میں نے انہیں قریب سے دیکھا اور جانا، اور میرے لیے وہ ہمیشہ ایک ناقابلِ فراموش دوست اور نظریاتی سنگت کے طور پر رہیں گے۔ ان کی ذات میرے لیے ایک تحریک، ایک فکر، اور ایک رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔وہ آج ہمارے درمیان جسمانی طور پر موجود نہیں، لیکن ان کے نظریات، ان کی جرأت، اور ان کی آواز امر ہے۔
اوہ ہمیں باور کراتے ہیں کہ حقیقی انقلابی کے لیے موت انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ جو لوگ نظریات اور عظیم مقاصد کے لیے جیتے ہیں، وہ جسمانی فنا کے بعد بھی تاریخ کے دھارے میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ اپنے پیچھے ایسے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا چراغ بن جاتے ہیں۔ ان کا خواب ایک آزاد، باوقار اور خودمختار بلوچ وطن تھا۔ یہ انہوں نے اپنی سوچ، اپنے عمل اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اسی ارمان کی تکمیل کے لیے وقف کیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ غلام قومیں صرف اسی وقت آزادی کا سورج دیکھ سکتی ہیں جب وہ اپنی صفوں میں نظریاتی استقامت، شعور اور مزاحمت کی طاقت پیدا کریں۔ وہ ہمیں یہ باور کراتے ہیں غلامی کوئی تقدیر نہیں بلکہ ایک زنجیر ہے،اور آزادی کی جدوجہد ایک لمبا اور کٹھن سفر ہے، جو خون، قربانی اور عزم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ آخری لمحے تک اس یقین کے ساتھ ڈٹے رہے کہ جدوجہد کو بغیر رُکنے، بغیر جھکنے اور بغیر کمزور پڑنے کے آگے بڑھانا ہی ایک آزادی دوست کا سب سے بڑا فرض ہے۔
اس کی فکر ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ آزادی صرف سیاسی نعرہ نہیں بلکہ ایک ہمہ جہت تصور ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی تاریخ اور اپنی شناخت کو غلامی کے اثرات سے پاک کریں۔
اگرچہ وہ جسمانی طور پر ہم سے جدا ہو گئے، لیکن وہ ہر اُس لمحے میں زندہ ہیں جب کوئی بلوچ آزادی کا نعرہ بلند کرتا ہے، جب کوئی ماں اپنے شہید بیٹے کو فخر سے یاد کرتی ہے، اور جب کوئی نوجوان دشمن کے جبر کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں کیونکہ نظریات کبھی مرتے نہیں۔ان کی زندگی اور فکر ہمیں یہ عہد دہرانے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ان کے نظریات کو حقیقت بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں۔ ہم اس جدوجہد کو اسی شدت اور عشق سے آگے بڑھائیں جس شدت اور عشق کے ساتھ اس نے نے اپنی زندگی گزاری۔ کیونکہ یہی ان کے ساتھ حقیقی وفاداری ہے، یہی ان کی قربانی کا اصل صلہ ہے، اور یہی بلوچ قومی تحریک کا ناقابلِ شکست عزم ہے۔
دھرتی محض مٹی کا نام نہیں، یہ تاریخ کا آئینہ، قربانیوں کا استعارہ، اور خوابوں کا وہ بستر ہے جس پر نسلیں اپنی شناخت کا نقش ثبت کرتی ہیں۔ اس دھرتی کی رگوں میں بہتا ہوا خون کبھی خاموش نہیں رہتا، یہ وقت کے ہر طوفان کے باوجود اپنے وجود کا اعلان کرتا ہے۔ بلوچ دھرتی کی تاریخ بھی اسی ابدی مزاحمت کا باب ہے۔ صدیوں سے اس سرزمین نے سامراجی پنجوں، نوآبادیاتی شکنجوں اور داخلی غداریوں کے زخم سہے ہیں، لیکن ہر زخم کے ساتھ اس کی روح اور زیادہ جری، زیادہ زندہ اور زیادہ بیدار ہوئی ہے۔ اسی دھرتی کے بطن سے ایسے کردار جنم لیتے ہیں جو غلامی کے اندھیروں میں روشنی کے مینار بن کر اُبھرتے ہیں۔ انہی میناروں میں سے ایک میر قادر بلوچ ہیں وہ مٹی کی خوشبو جو وقت کی گرد سے ماند نہیں پڑتی، وہ امرت دھار جو سامراجی زہر کے باوجود اپنی زندگی بخش تاثیر کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ان کا وجود اس دھرتی کے اُس خوابیدہ شعور کا اظہار ہے جو نوآبادیاتی نظام نے زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کی لیکن مکمل طور پر کبھی شکست نہیں دے سکا۔ وہ اس حقیقت کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ غلامی محض جسموں کو جکڑ سکتی ہے، روحوں کو نہیں۔ غلام قوموں کے جسم قید میں ہوتے ہیں، لیکن اگر روح زندہ رہے، اگر کمٹمنٹ برقرار رہیں، تو سامراج کی سب سے بڑی طاقت بھی انہیں مٹا نہیں سکتی۔ وہ اس زندہ روح کے امین تھے۔ ان کے دل میں دھڑکنے والا ہر خیال آزادی کے لئے تھا، ان کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ مزاحمت کا علمبردار تھا، اور ان کا ہر قدم غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لئے اُٹھتا تھا۔وہ اپنی سرزمین کو محض ایک جغرافیائی خطے کے طور پر نہیں دیکھا، بلکہ اسے ایک جیتی جاگتی ماں سمجھا جس کی کوکھ میں ہزاروں قربانیوں کی کہانیاں پوشیدہ ہیں۔ ان کے نزدیک دھرتی سے وفاداری محض ایک جذباتی تعلق نہیں بلکہ ایک سیاسی اور فکری ذمہ داری تھی۔ وہ بلوچ مزاحمت کی اس روایت کے وارث تھے جو بابا خیر بخش مری شہید غلام محمداور دیگر انقلابی رہنماؤں سے ہوتی ہوئی ان کے سینے میں دھڑکتی تھی۔
غلامی کی سیاہ شبی کے وہ ایک ایسے چراغ تھے جس کی لو سامراجی آندھیوں کے باوجود بجھ نہ سکی۔ ان کا کردار اس دھرتی کے اُن رنگوں کی مانند تھا جو وقت کے ہر موسم میں اپنی اصل خوشبو کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ خوشبو محض زمین سے نہیں بلکہ اُن قربانیوں سے جنم لیتی ہے جو قوم کے سپوت اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر دھرتی کے دامن میں دفن کرتے ہیں۔ اس نےنے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر قوم اپنی قربانیوں کو یاد نہ رکھے، اگر وہ اپنی تاریخ سے غافل ہو جائے، تو غلامی کے اندھیرے ہمیشہ کے لیے اس کی قسمت بن جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ مزاحمت محض دشمن کے خلاف جنگ نہیں بلکہ خود اپنے اندر کی کمزوریوں کے خلاف بھی بغاوت ہے۔ انہوں نے بلوچ سیاست میں موجود اس سمجھوتہ پسندی کو ہمیشہ للکارا جو قومی مفادات کو وقتی سیاسی فائدوں پر قربان کر دیتی ہے۔ ان کے نزدیک آزادی نصف قدموں سے نہیں بلکہ پورے قدم کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قومیں اُس وقت تک آزاد نہیں ہوتیں جب تک وہ اپنی آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔
میر قادر بلوچ آج جسمانی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کی فکر اور ان کے خواب زندہ ہیں۔ ان کی قربانی اس بات کا اعلان ہے کہ نظریات مر نہیں سکتے، انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آج بھی بلوچ دھرتی کے اس امرت دھار کی مانند بہہ رہے ہیں جو ہر نئی نسل کو زندگی، حوصلہ، اور مزاحمت کا پیغام دے رہا ہے۔ غلامی کے اندھیروں کے باوجود ان کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سامراجی ظلم اور داخلی غداری کبھی کسی قوم کے اصل وجود کو مٹا نہیں سکتے۔
تاریخ کے صفحات ہمیشہ ان ہی کرداروں کے خون سے روشن رہتے ہیں جو اپنی ذات کو مٹا کر قوم کے لیے زندہ رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ ایسے لوگ محض انسان نہیں ہوتے، وہ ایک فکر، ایک نظریہ، اور ایک ایسی سرمدی صدا ہوتے ہیں جو وقت کی سرحدوں کو توڑ کر آنے والی نسلوں کے دل و دماغ میں گونجتی رہتی ہے۔
تین دسمبر کی وہ تاریک شب محض ایک رات نہیں تھی، بلکہ صدیوں پر محیط غلامی کے سائے میں چھپی ہوئی وہ گھڑی تھی جس نے ایک جسم کو فنا کیا مگر ایک نظریے کو امر کر دیا۔۔ جسم کا مٹ جانا محض مٹی کا مٹی سے مل جانا تھا، مگر فکر کا ابھر جانا ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔
اس نے اپنی فکر سےاس مٹی کو ایسا امرت بخشا کہ اب یہ سرزمین محض خاک کا ڈھیر نہیں بلکہ قربانیوں کے رنگ سے رنگا ہوا ایک جیتا جاگتا گواہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ موت ایک انجام نہیں بلکہ ایک تسلسل ہے۔ ایک انقلابی کے لیے جسمانی فنا محض ایک مرحلہ ہے، اصل زندگی اس کی فکر اور جدوجہد کی تکرار میں پوشیدہ ہے۔
بلوچ قومی تاریخ میں ان کا نام اُن رہنماؤں کی صف میں آتا ہے جنہوں نے کبھی سمجھوتے کو قبول نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ غلامی کے ساتھ سمجھوتہ، بقا کے لیے زہر پینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہ باور کرایا کہ آزادی کی جدوجہد میں آدھے قدم پیچھے ہٹنا، صدیوں کی محکومی کو طول دینے کے برابر ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی انقلابی اپنی ذات کو فنا کر کے امر ہو جاتا ہے۔ اس کی موت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا نظریہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ وہ اپنی قوم کے اجتماعی شعور کا حصہ بن جاتا ہے، اور وقت کی سرحدیں اس کے افکار کو قید نہیں کر سکتیں۔آج جب ہم ان کی جدوجہد کو یاد کرتے ہیں تو یہ محض تعزیت کا لمحہ نہیں بلکہ تجدیدِ عہد کا موقع ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کا خواب صرف اسی وقت شرمندۂ تعبیر ہو سکتا ہے جب ہم ان کے نظریے کو اپنائیں اور اپنی آزادی کے لیے وہی جذبہ اور قربانی پیش کریں جو انہوں نے کی۔ وہ فنا نہیں ہوئے، وہ امر ہو گئے ہیں۔ ان کا خون اس مٹی کے ذروں میں رچ بس گیا ہے، ان کی فکر ہر بلوچ کے شعور کا حصہ بن چکی ہے، اور ان کا نام تاریخ کے سنہری باب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ ایک روشن چراغ ہیں جو آنے والی نسلوں کو ظلمت کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا رہے گا، اور ان کا نظریہ ایک ایسی صدا ہے جو کبھی خاموش نہیں ہو گی۔

